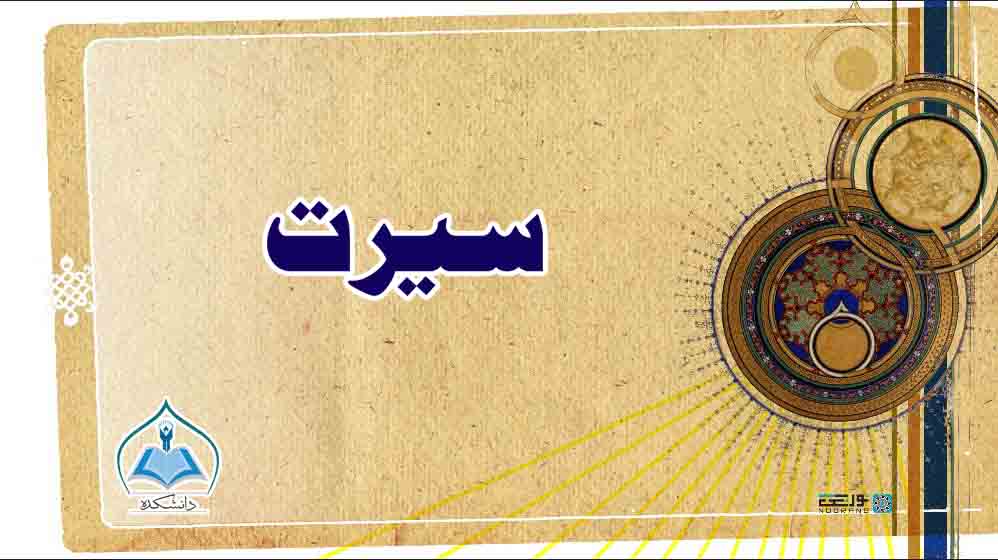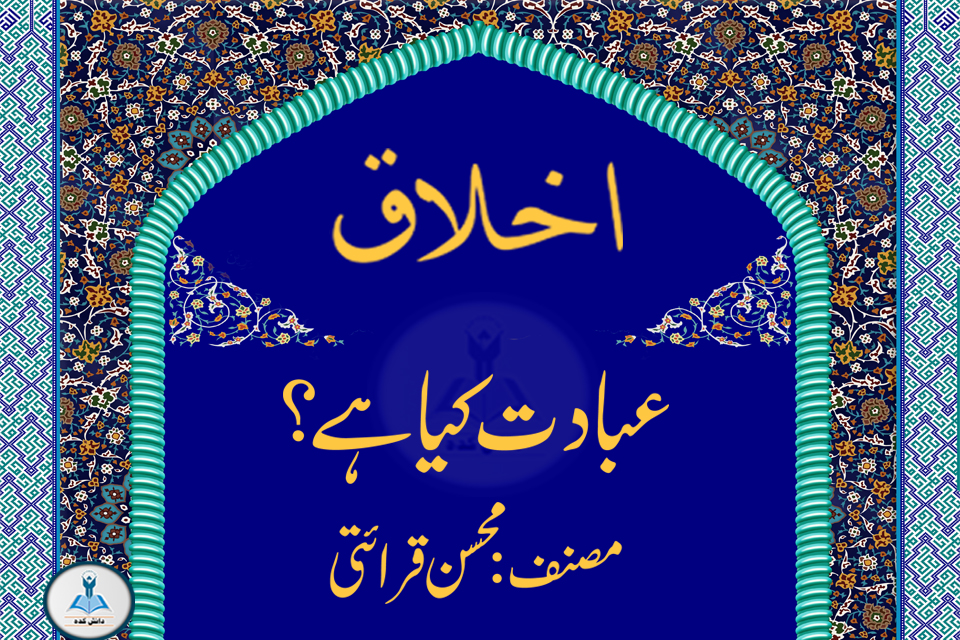اربعینِ حسینی با کاروانِ عشق

(ایم صادقی)
قریبا چودہ صدیاں بیت گئیں لیکن واقعہ کربلا آج بھی اسی طرح زندہ ہے، آج بھی غمِ حسین علیہ السلام میں قلب فگار ہیں اور آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں۔ اگر ایک سروے انجام دیا جائے کہ جسکا عنوان یہ ہو کہ” کس شخصیت کے لئے دنیا میں سب سے زیادہ آنسو بہائے گئے، بہائے جاتے ہیں اور بہائے جائیں گے” تو یقینا جواب میں حسین علیہ السلام کا نام لیا جائے گا۔ واقعہ کربلا سے لے کر آج تک اور تا قیامت، یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جسے یاد رکھا گیا اور رکھا جائے گا۔ جب اور جہاں حسین (ع) کا نام آئے گا وہاں دیگر شہیدان و غازیانِ کربلا کو بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔
کربلا وہ سرزمیں کہ جسکا نام سنتے ہی دل سے اک آہ سی اٹھتی ہے۔ کربلا وہ ریگستانِ خشک و بےآب جو انسانیت اور کمال کا بیکراں سمندر یے کہ جس کے اندر عظیم گوھر، مظلومیت کے غلاف میں پنھاں ہیں جنکو ڈھونڈنے کے لئے چشمِ بصیرت کی ضرورت ہے، ان کی تلاش کے لئے ماہر غواص چاہییں، کیونکہ سمندر کی تہہ میں اترنے کے لئے بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں، اسکے لئے جوانمردی اور معرفت کی ضرورت ہے۔
ہر سال محرم آتا ہے اور ہمارے دلوں پر لگے اس زخم کو تازہ کر جاتا ہے، وہ زخم کہ جس پر سال کے باقی مہینوں میں ہلکا سا کھرنڈ بن جاتا ہے لیکن محرم کے آتے ہی اس زخم سے تازہ
ہر سال محرم آتا ہے اور ہمارے دلوں پر لگے اس زخم کو تازہ کر جاتا ہے، وہ زخم کہ جس پر سال کے باقی مہینوں میں ہلکا سا کھرنڈ بن جاتا ہے لیکن محرم کے آتے ہی اس زخم سے تازہ خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، بارِ الھا، یہ کیسا غم ہے جو کم ہی نہیں ہوتا، زمانے کا دستور ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اول روزِ مرگ، پھر سوم، اسکے بعد دسواں، اور آخر میں چالیسواں، سال کے بعد برسی ایک سال، دو سال، تین سال، دس سال، بیس سال اور پھر فراموشی۔ گر نہیں ہے تو امام حسین (ع) کے لئے نہیں ہے اور نہ ہو گی، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟
خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، بارِ الھا، یہ کیسا غم ہے جو کم ہی نہیں ہوتا، زمانے کا دستور ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اول روزِ مرگ، پھر سوم، اسکے بعد دسواں، اور آخر میں چالیسواں، سال کے بعد برسی ایک سال، دو سال، تین سال، دس سال، بیس سال اور پھر فراموشی۔ گر نہیں ہے تو امام حسین (ع) کے لئے نہیں ہے اور نہ ہو گی، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر سال امام حسین (ع) اور ان کی اولاد و اصحاب کے لئے یہ ایام منائے جاتے ہیں اور ہر آنے والے سال میں پچھلے سالوں سے زیادہ زور و شور سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ چودہ سو سال سے یہ غم اسی طرح منایا جا رہا ہے، یہ صریح معجزہ ہے سب کو نظر آتا ہے سوائے ان کے کہ جن کے دلوں پر خدا نے "صم بکم عمی” کی مہر لگا دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بصیرت سے محروم ہیں، جو ان ہستیوں کی درست شناخت نہیں رکھتے۔
اس سال بھی محرم آیا اور ان تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے آج ۱۹ صفر المظفر کو ہم شب اربعین حسینی پہ آ پہنچے ہیں۔ "شب اربعین” حسین بن علی (ع) کی شھادت کی چالیسویں شب کو کہا جاتا ہے، اور روز اربعین” انکے چہلم کا دن ہے۔ اس شب و روز میں امام (ع) کے عاشقان و پیروان ذکر مصیبت کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ یہ وہ حق و عشق کا راستہ ہے کہ جو اس کو جاری رکھے گا وہ کبھی منحرف نہیں ہو گا۔
اولین
اس دن زیارتِ امام حسین (ع) پڑھنا مستحب ہے اور یہ زیارت "زیارتِ اربعین” کے نام سے معروف ہے، شیخ طوسی رہ نے زیارتِ اربعین کی سند کو حضرت امام صادق (ع) سے کچھ اسطرح سے نقل کیا ہے، "السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه…، اس کی سند موثق ہے کیونکہ اس مطلب کو قرنِ پنجم کے انتہائی معتبر شیعہ عالم شیخ طوسی رہ نے نقل کیا ہے،
اربعين:
روایات کے مطابق امام حسين (ع) کی شهادت کے بعد انکے اولین اربعین کے دن صحابی رسول خدا (ص)، جابر بن عبداللہ انصاری اور عطیہ عوفی امام حسین کی تربت کی زیارت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بعض کتب میں نقل ہوا ہے کہ اسی اربعین کے دن کربلا کے اسراء اہل بیت عصمت و طہارت کا کاروان جو اس مصیبت عظیم کے بعد شام سے مدینہ واپس جا رہا تھا، راستے میں ان کی ملاقات جابر بن عبداللہ سے ہوتی ہے، البتہ یہاں اس نکتے کہ طرف اشارہ کرتے چلیں کہ بعض مورخان اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جن میں مرحوم محدث قمی شامل ہیں، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے "منتھی الآمال” میں مختلف دلائل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہ جابر سے اہل بیت کی یہ ملاقات اولین اربعینِ حسینی پہ نہیں ہوئی، البتہ اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے جابر بن عبداللہ کی اہل بیت (ع) سے اولین اربعین پہ ہی ملاقات ہوئی تھی، اور جابر قبرِ امام حسین (ع) کا پہلا زائر ہے۔
اس دن زیارتِ امام حسین (ع) پڑھنا مستحب ہے اور یہ زیارت "زیارتِ اربعین” کے نام سے معروف ہے، شیخ طوسی رہ نے زیارتِ اربعین کی سند کو حضرت امام صادق (ع) سے کچھ اسطرح سے نقل کیا ہے،
السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه…،”
اس کی سند موثق ہے کیونکہ اس
پيامبر حکيم (ص) فرماتے ہیں، «من اخلص لله اربعين يوماً فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»: جو شخص اپنے تمام اعمال کو چالیس دن تک صرف اور صرف خدا کے لئے خالص کر لے خدا حکمت کو اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔
مطلب کو قرنِ پنجم کے انتہائی معتبر شیعہ عالم شیخ طوسی رہ نے نقل کیا ہے، اور بطور طبیعی جو جایگاہ زیارتِ اربعین کی آج شیعوں کے درمیان ہے وہ پہلے نہیں تھی وگرنہ جابر کی طرح اور لوگ بھی بالخصوص اس دن امام کی قبرِ مبارک کے زائر ہوتے، یہ سنت آج بھی عراقی و غیر عراقی لوگوں کے درمیان مرسوم ہے اور اس دن پوری دنیا سے عاشقانِ امام حسین (ع) انکے مرقدِ مطھر پر جمع ہوتے ہیں۔
دینی تعلیمات میں اربعین کے عدد کی اہمیت:
دینِ اسلام میں بہت سے اہم واقعات میں اربعین کی تعبیر موجود ہے، جسکا ایک نمونہ یہ ہے کہ رسول خدا (ص) کی بعثت کے وقت عمرِ مبارک چالیس سال تھی، کہا گیا ہے کہ چھل کا عدد انسان کی عمر میں بلوغ اور رشدِ فکری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن میں پروردگار کے ساتھ «میقات» موسی (ع) چھل دن تک تھی۔ روایات میں نقل ہے کہ حضرت آدم چھل دن رات کوہِ صفا پر اپنے پروردگار کے سامنے سجدے میں رہے۔ (1)۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ اپنی دعا کی قبولیت کے لئے چالیس روز و شب گریہ و زاری کیا کرتے تھے۔ (2)۔ پيامبر حکيم (ص) فرماتے ہیں، «من اخلص لله اربعين يوماً فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»: جو شخص اپنے تمام اعمال کو چالیس دن تک صرف اور صرف خدا کے لئے خالص کر لے خدا حکمت کو اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔
روایات میں نقل ہے چالیس
اربعین کے فلسفے کے بارے میں اور اس عدد کے اسرار و رموز کے سلسلے میں اسقدر روایات ہیں کہ قابلِ شمارش نہیں۔ اور اگر آپ تمام انبیاء و آئمہ و اوصیاء کی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ انکے ولادت و وفات یا شھادت کے ایام تو منائے جاتے ہیں لیکن چہلم کسی کا نہیں منایا جاتا، یہ اعزاز صرف سید الشھداء کو حاصل ہے۔
احادیث کے حفظ کرنے کی بہت فضیلت ہے، ایک روایت پیامبرِ گرامی (ص) سے نقل کی گئی ہے کہ” میری امت میں سے جو شخص چالیس احادیث یاد کر کے اس نیت سے کہ ان احادیث کو اوام اللہ میں استفادہ کرے گا تو خداوند عالم اسکو روزِ قیامت چالیس علماء و فقھا کے ساتھ محشور کرے گا۔ امام علی (ع)سے روایت ہے کہ”اگر چالیس مومن میری بیعت کر لیتے تو میں قیام کر لیتا”(3)۔ روایت میں ہے کہ جو شراب پئے چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، ایک دوسری روایت میں نقل ہے کہ جو شخص چالیس دن تک گوشت نہ کھائے وہ بداخلاق ہو جاتا ہے اور جو چالیس دن مسلسل گوشت کھائے شقی القلب ہو جاتا ہے۔ جو چالیس دن رزقِ حلال کھائے خداوند اسکے قلب کو نورانی کر دیتا ہے۔” رسول خدا (ص) نے فرمایا کہ جو حرام لقمہ کھائے خدا کی درگاہ میں چالیس دن تک اسکی دعا قبول نہیں ہوتی۔(4) اربعین کے فلسفے کے بارے میں اور اس عدد کے اسرار و رموز کے سلسلے میں اسقدر روایات ہیں کہ قابلِ شمارش نہیں۔ اور اگر آپ تمام انبیاء و آئمہ و اوصیاء کی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ انکے ولادت و وفات یا شھادت کے ایام تو منائے جاتے ہیں لیکن چہلم کسی کا نہیں منایا جاتا، یہ اعزاز صرف سید الشھداء کو حاصل ہے۔ اسی لئے شیعہ ان کی زیارت کرنے، پڑھنے اور عزاداری و ماتم میں کوتاہی نہیں کرتے، امام حسن عسكرى علیهالسلام
مومن کو چاہیئے کہ وہ بھی اپنے آپ کو جابر بن عبدالله انصارى کی اس حدیث میں اپنے عمل کے ذریعے شامل کر لے کہ جابر فرماتے ہیں، ” جو جس قوم اور اسکے عمل کو چاہتا ہے وہ روزِ قیامت اسی کے ساتھ محشور ہو گا” ہم حسین علیه السلام کے چاہنے والے ہیں، کیوں؟ اسلئے کہ حسین کو خدا چاہتا ہے، اسکا رسول (ص) چاہتا ہے، سیدتہ النساء (ع) چاہتی ہیں، تمام انبیاء الھی چاہتے ہیں، جن و ملک و انس اور حتیٰ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ حسین (ع) کا عاشق ہے۔
نے زیارت اربعین کو ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔
جی ہاں یہ زیارت اربعین ہی ہے جو خالص مومن کو دوسروں سے جدا کرتی ہے، اہلبیت علیه السلام کے دوستوں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے اور یہ ایامِ حسینی ہی ہیں یہ اربعینِ حسینی ہی ہے جسکو زندہ رکھنے سے ہم بھی زندہ ہیں، اور مومن واقع وہی ہے جو حسین علیه السلام کی نهضت کو زندہ رکھے، اور اسکی قدردانی، ھدف اور شرکت میں کوتاہی نہ کرے۔ مومن کو چاہیئے کہ وہ بھی اپنے آپ کو
جابر بن عبدالله انصارى کی اس حدیث میں اپنے عمل کے ذریعے شامل کر لے کہ جابر فرماتے ہیں، ” جو جس قوم اور اسکے عمل کو چاہتا ہے وہ روزِ قیامت اسی کے ساتھ محشور ہو گا” ہم حسین علیه السلام کے چاہنے والے ہیں، کیوں؟ اسلئے کہ حسین کو خدا چاہتا ہے، اسکا رسول (ص) چاہتا ہے، سیدتہ النساء (ع) چاہتی ہیں، تمام انبیاء الھی چاہتے ہیں، جن و ملک و انس اور حتیٰ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ حسین (ع) کا عاشق ہے۔ ہمارے دل سالار شهیدان کے لئے بےتاب، آنکھیں انکی مظلومانه ترین شهادت پر گریاں ہیں۔ آخر میں پروردگار سے دعا ہے کہ تمام مومنوں کو، "کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین”۔
1۔ مستدرک وسائل، ج9، ص329
2۔ مستدرک، ج5، ص239
3۔ الاحتجاج، ص84
4۔ مستدرک وسائل، ج5، ص217